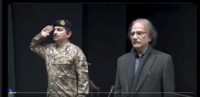قیام پاکستان
قیام پاکستان کا سیاسی و قانونی پس منظر
بقلم [ بنت نذير ]
پاکستان بننے سے پہلے مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے مسلمانوں پر ہندوؤں کی حکومت تھی مسلمانوں کو آزادی حاصل نہیں تھی ان پر ظلم کیے جاتے تھے چنانچہ ان کو ان کے حقوق حاصل نہیں تھے.
اگست 1947ء میں پاکستان کا قیام ان معنوں میں ایک منفرد واقعہ تھا کہ اس زمانے میں دنیا کے مختلف خطوں میں جو دیگر ممالک آزاد ہوئے وہ پنجۂ غلامی میں جانے سے پہلے بھی ایک ملک کی حیثیت سے اپنا جداگانہ وجود رکھتے تھے ۔ ان ملکوں نے آزادی کی تحریکیں چلائیں اور کامیابی کے بعد اپنے سابقہ تشخص کو دوبارہ حاصل کرلیا۔ ان ممالک کے برعکس پاکستان 1947ء سے پہلے کبھی بھی ایک ملک کی حیثیت سے اپنا جداگانہ تشخص نہیں رکھتا تھا۔ پاکستان میں شامل علاقے برصغیر کا حصہ تھے اور برصغیر پر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنی فوج کے ذریعے ایک سو سال کے عرصے میں اپنا قبضہ مکمل کرکے اس کو سلطنت برطانیہ کے سپرد کردیا تھا۔ 1857ء میں یہ قبضہ مکمل ہوا اور اس کے ساتھ ہی انگریزی استعمار کے خلاف برصغیر کے طول و عرض میں آزادی کے لیے آوازیں اور تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔1857ء سے 1947ء تک کے نویں سال کے عرصے میں مسلم سیاسی شناخت ایک جداگانہ اور نمایاں پروگرام کے طور پر اجاگر ہوئی جس کے واضح سیاسی اور اقتصادی عوامل موجود تھے۔ انگریزی استعمار کی تعمیر و تشکیل کے دوران ابتدا ہی میں یہ بات واضح ہوگئی تھی کہ اب جب کہ پہلی مرتبہ ہندوستان میںاستعماری مقاصد ہی کے تحت نمائندہ اداروں کا قیام عمل میں آرہا ہے اور ساتھ ہی ایسی انتظامی اور اقتصادی پالیسیاں متعارف کی جارہی ہیں جن کے نتیجے میں شہری علاقوں میں نئی سرکاری زبان یعنی انگریزی میں دسترس رکھنے والوں کی اہمیت اجاگر ہورہی ہے اور دیہی علاقوں میں ایک نئی اقتصادی اشرافیہ وجود میں آرہی ہے۔ ان نئے رجحانات سے خود کو لاتعلق اور غافل نہیں رکھا جاسکے گا۔ ان دونوں سماجی طبقات کے لیے ضروری تھا کہ نئے وجود میں آنے والے نمائندہ اداروں تک پہنچ حاصل کریں تاکہ اپنے طبقات کے مفادات کا تحفظ کرسکیں۔ یہ اسی مرحلے پر ہوا کہ مسلمانوں کے بااثر طبقات کو پہلی مرتبہ ہندوستان کی مجموعی آبادی میں اپنے اقلیت ہونے کا شدت کے ساتھ احساس ہوا۔ اس احساس کا اولین اظہار سرسید احمد خان کی تحریروں میں ہوا جبکہ بعد میں مسلم سیاسی قیادت کا بڑا حصہ اور 1904ء میں بننے والی مسلم لیگ اس احساس کے ترجمان بنے۔
قائداعظم محمد علی جناح ایک جدید ذہن کے حامل سیاستدان تھے۔ انہوں نے وکالت کی تعلیم کی غرض سے جو عرصہ انگلستان میں گزارا وہ ان کے ذہن کی تشکیل اور ان کے سیاسی تصورات کی تعمیر میں بہت ممد و معاون ثابت ہوا۔ انگلستان میں اپنے قیام کے دوران وہ لبرل سیاسی مفکرین کے خیالات سے متاثر ہوئے ۔انہوں نے برطانوی پارلیمانی نظام کا تفصیلی مطالعہ کیا ۔ساتھ ہی انہوں نے اس نظام کی داخلی حرکیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ برطانیہ میں مذہبی مناقشات کو حل کرنے کی غرض سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور یہ کہ ریاست نے خود کو مذہبی امور کے حوالے سے مکمل طور پر غیر جانبدار بنا کر اور ساتھ ہی مذہبی آزادیوں کی ضمانت فراہم کرکے معاشرے کوکس طرح دائمی امن سے ہمکنار کردیا ہے۔ہندوستان واپسی پر قائداعظم نے جب عملی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو ابتدا ہی میں ایک بہت بڑا سوال ان کے سامنے آ ٓکھڑا ہوا۔ ہندوستان میں مسلمان ایک اقلیت کی حیثیت رکھتے تھے جب کہ کوئی نو دس صدیوں تک مسلمان بادشاہ ہندوستان پر حکمرانی کرتے رہے تھے۔ اس پورے عرصے میں ہندوستان کے مسلمانوں میں دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا رجحان بھی موجود رہا تھا جب کہ اپنے مذہبی معاملات میں وہ اپنے علیحدہ طرز فکرو عمل کے بھی حامل رہے تھے۔ یہ دونوں رجحانات ہمیشہ ہی ایسے معاشروں میں پاۓ جاتے رہے ہیں جہاں ثقافتی تنوع موجود ہوتا ہے ہندوستان بھی اس ثقافتی تنوع کا حامل تھا اور یہ کوئ غیر معمولی اور ہندوستان سے مخصوص بات نہیں تھی لیکن انگریز کئ آمد کے بعد نمائندہ اداروں کے قیام کے نتیجے میں اب جبکہ قانون سازی اور انتظامی امور کی انجام دہی ان اداروں کے سپرد ہونے والی تھی تو پہلی مرتبہ ہندوستان کا ثقافتی تنوع سیاسی تقسیم کی بنیاد بننا شروع ہوا.
قائداعظم کا خیال تھا کہ نمائندہ اداروں میں اگر جمہوری اصولوں کو ہندوستان کے معروضی حالات سے لاتعلق ہو کر نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتیجے میں ہندوئوں کی ثقافتی اکثریت ان کی سیاسی اکثریت کا راستہ ہموار کرے گی جب کہ مسلمان ثقافتی اقلیت ہونے کے ناطے سیاسی اقلیت بھی قرار پائیں گے۔ اس تضاد کے حل کے لیے انہوں نے جو حکمت عملی وضع کی اس کے دو نمایاں قانونی و سیاسی پہلو تھے ۔حکمت عملی کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ قائداعظم کو معلوم تھا کہ جمہوری سیاسی نظاموں میں اس امر کی بھی گنجائش موجود ہوتی ہے کہ آبادی کے کسی حصے کی کمتر تعداد کو نسبتاً زیادہ نمائندگی دے کر اس کا اعتماد بھی حاصل کیا جاسکتا ہے اور اس کو قوم سازی کے عمل میں شریک بھی رکھا جاسکتا ہے۔ سیاسی زبان میں اس کو ایجابی اقدام کہا جاتا ہے، یعنی ایسا اقدام جس کے ذریعے کسی حلقے کو اس کے منطقی حق سے زیادہ دے کر اس کے اعتماد کو جیتا جائے(اس کی ایک بہت اچھی مثال ہمارے موجودہ آئینی نظام سے دی جاسکتی ہے جس میں خواتین کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں عام انتخابات میں کھڑے ہونے کے حق کے باوجود اضافی طور پر سولہ فیصد نشستیں اس لیے دی گئی ہیں کیونکہ پاکستان کے پسماندہ اور مردانہ غلبے کے حامل معاشرے میں خواتین کے لیے عام انتخابات میںاس آزادی کے ساتھ مہم چلانا ممکن نہیں ہے جس آزادی کے ساتھ مرد حضرات اپنی مہم چلا سکتے ہیں)قائداعظم نے سیاسی میدان میں قدم رکھنے کے فوراً بعد ہی سے مسلمانوں کے لیے کسی بھی سیاسی دروبست میں ایک ایسی نمائندگی کی تجویز پیش کی جو ان کو انکی اقلیتی حیثیت کی بنا پرنظر انداز کردیے جانے سے محفوظ رکھ سکے۔ چنانچہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تقریباً چوبیس فیصد آبادی کے لیے وہ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں تینتیس فیصد نمائندگی کی وکالت کرتے رہے۔
یہ1914ء کا لکھنو پیکٹ ہو یا 1927ء میں پیش کی جانے والی ’دہلی مسلم تجاویز‘ ، قائداعظم کے چودہ نکات ہوں یا لندن کی گول میز کانفرنس کے اجلاسوں میں پیش کردہ دلائل ، یا پھر بعد کے برسوں میں سامنے آنے والے سیاسی فارمولے ، کم و بیش ان تمام مراحل میں قائداعظم کی جانب سے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی نمائندگی کے تناسب کی وکالت کی گئی جو ان کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرسکتی۔ انہوں نے پہلے مسلمانوں کو ایک اقلیت کے طور پر پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے سیاسی حقوق کی وکالت کی ۔ اور بعد میں انہوں نے مسلمانوں کے ایک جداگانہ قوم ہونے کا موقف اختیار کیا تاکہ بین الاقوامی قوانین کی رو سے جو حقوق قوموں کو حاصل ہوتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی ان کی وکالت کی جاسکے۔ لیکن خواہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک اقلیت سمجھا ہو یا ایک اگلے مرحلے پر ان کو قوم قرار دیا ہو، قائداعظم کا نکتہ نظر مذہبی منافرت پر مبنی اورفرقہ ورانہ کبھی بھی نہیں رہا۔ ان کے پورے سیاسی کیریئر کو اٹھا کر دیکھ لیں انہوں نے کبھی بھی ہندوؤں کے لیے تحقیر یا تذلیل کا کوئی ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا ۔ تحقیر اور تذلیل تو دور کی بات انہوں نے بارہا اپنی گفتگوؤں میں اور اپنے بیانات میں ان کے لیے احترام کے الفاظ استعمال کیے یہاں تک کہ 7 مارچ 1947ء کو انہوں نے میمن چیمبر میں اظہار خیال کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ:
’’ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں عظیم ہندو کمیونٹی اور ان سب کا جس کے وہ علمبردار ہیں،احترام کرتا ہوں۔ ان کا اپنا عقیدہ ہے ۔اپنا فلسفہ ہے ۔ اپنا عظیم کلچر ہے. لیکن دونوں مختلف ہیں. میں ہندوستان کے لیے لڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ مسئلے کا واحد حل ہے.
قائداعظم نے کہا کہ اب تک جو میں سمجھ سکا ہوں دلی میں مسلم لیگ کے حلقے پرامید ہیں.
غالباً قائداعظم کی اسی سوچ کے پیش نظر مسلم لیگی قیادت نے بلآخر تقسیم بند کے اس منصوبے کو قبول کر لیا جس کا علان آل انڈیا ریڈیو سے نشری تقریروں کے ذریعے کیا گیا. یوں پاکستان کے قیام کی راہ ہموار ہوئ اور 14 اگست 1947ء کو اس کا وجود عمل میں آیا.